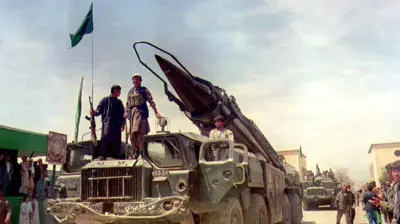بنگلہ دیش کے قیام کے 50 برس اور پاکستانی جنگی قیدی: کچھ فرار ہونے میں کامیاب، کچھ کے لیے ’جنگ کبھی ختم نہ ہوئی‘

- مصنف, فرحت جاوید
- عہدہ, بی بی سی اردو ڈاٹ کام، اسلام آباد
- مطالعے کا وقت: 18 منٹ
ریل گاڑی انڈیا کے ایک سٹیشن پر رکی تو اندر داخل ہونے والے انڈین فوجی افسر نے بلند آواز میں پوچھا، ’کسی نے کرنسی تبدیل کروانی ہے تو بتائے۔‘ اس ڈبے میں موجود پاکستانی فوج کے کئی افسران نے اپنی جیبیں ٹٹولیں اور جو پیسے تھے وہ انڈین فوجی کے ہاتھوں ان کی کرنسی میں تبدیل کروا دیے۔
یہ ٹرین اس وقت مشرقی پاکستان کے ساتھ انڈین سرحدی علاقے بینگان سے انڈین ریاست اترپردیش جا رہی تھی۔ ٹرین میں پاکستانی فوج کے ایک افسر میجر طارق پرویز بھی شامل تھے۔
میجر طارق پرویز نے رقم لی اور اسے اپنی قمیض کے مختلف حصوں میں چھپا لیا۔ ان کے کئی ساتھی فوجی افسر کھانے پینے کی اشیا خرید رہے تھے مگر وہ اپنے ذہن میں کوئی اور ہی منصوبہ بُن رہے تھے۔
یہ 1971 کا دسمبر تھا اور پاکستان نے کچھ دن پہلے ہی انڈیا کے خلاف ہتھیار ڈالنے کے معاہدے پر دستخط کیے تھے جس کے بعد اُس وقت دنیا کی سب سے نئی ریاست بنگلہ دیش وجود میں آئی تھی۔
اس شکست کے بعد پاکستان کے ہزاروں فوجی جنگی قیدی قرار دیے گئے جن میں سے ماسوائے چند خوش قسمت فوجیوں کے باقی تمام نے اگلے کئی سال انڈیا کے مختلف فوجی کیمپوں میں زیر حراست گزارے۔
شکست کے بعد فوجیوں کی فتح گڑھ منتقلی
انڈین فوج کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے بعد پاکستانی فوج کے اہلکاروں کو بطور جنگی قیدی مختلف کیمپس میں بھیجنے کے مرحلے کا آغاز ہو گیا تھا۔
چونکہ بنگلہ دیشں میں فسادات اور پاکستانی فوجیوں پر حملوں کا خطرہ تھا، اور ایسے انتظامات بھی نہیں تھے جہاں طویل مدت کے لیے اتنی بڑی تعداد میں فوجی اہلکاروں کو رکھا جا سکے، اس لیے ان فوجیوں کو انڈیا منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔
میجر طارق پرویز اور ان کے کزن میجر نادر پرویز سمیت سینکڑوں افسران اور سپاہی اس ٹرین پر سوار تھے جو مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی بالآخر انڈیا کی ریاست اتر پردیش کی فوجی چھاؤنی فتح گڑھ پہنچی۔
End of سب سے زیادہ پڑھی جانے والی
یہاں جنگی قیدیوں کے لیے بنے ایک کیمپ میں ان افسران اور سپاہیوں نے اگلے سوا دو سال گزارنے تھے۔
قید سے فرار کے منصوبے تو اسی وقت بننے شروع ہو گئے تھے جب ہتھیار ڈالنے کی خبریں چھاؤنیوں سے ہوتی اگلے مورچوں تک پہنچی تھیں۔ کئی فوجیوں نے فرار کی کوشش بھی کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔
خیال رہے کہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہر جنگی قیدی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دشمن کی قید سے فرار کی کوشش کرے اور ایسا کرتے ہوئے پکڑے جانے پر اسے سزا نہیں دی جا سکتی۔

میجر طارق پرویز اور ان کے ساتھی اسی تاک میں رہے کہ کہیں کسی انڈین فوجی سے کوئی چُوک ہو اور وہ موقع ملتے ہی ٹرین سے بھاگ جائیں، مگر مجال ہے جو کوئی انڈین فوجی ٹس سے مس ہوا ہو۔
میجر طارق پرویز اور ان کے ہمراہ قیدیوں کو فتح گڑھ چھاؤنی کے کیمپ نمبر 45 میں رکھا گیا۔
اس کیمپ میں افسروں کے لیے دو لمبی بیرکس تھیں اور ایک بیرک کو چھ حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔
ایک حصہ جونیئر افسروں کی رہائش کے لیے تھا، جبکہ دوسرا حصہ تفریحی کمرے، تیسرا حصہ ڈائننگ ہال اور چوتھا حصہ اردلیوں کے لیے مختص کیا گیا۔
باورچی خانہ اور سٹور روم بھی ایک حصے میں تھے۔ دوسری بیرک کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک حصہ آٹھ فٹ لمبا تھا جس میں لکڑیوں سے پانچ غسل خانے بنائے گئے تھے جبکہ دوسرے حصے میں 43 افسران نے رہنا تھا۔
ان عارضی غسل خانوں کے ساتھ ایک گہری خندق والا بیت الخلا بھی بنایا گیا تھا۔ یہی وہ بیرک تھی جہاں میجر طارق پرویز قید ہوئے اور یہی وہ غسل خانے تھے جہاں سے فرار کا منصوبہ شروع ہوا۔
فرار کا منصوبہ کیسے بنا؟
میجر طارق پرویز بعد ازاں پاکستانی فوج میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے تک پہنچے۔ بنگلہ دیش کے قیام کے 50 برس ہونے کے موقع پر پاکستان کے جنگی قیدیوں کے ساتھ بیتے گئے واقعات کے بارے میں انھوں نے بی بی سی سے کیمپ نمبر 45 اور وہاں سے فرار کے بارے میں گفتگو کی۔
طارق پرویز نے بتایا کہ فرار کے لیے تیار پاکستانی فوجی افسروں نے پہلے تو کپڑوں کا ایک ایک جوڑا چھپایا۔ پھر کرنسی چھپائی گئی۔ ان افسران نے بطور قیدی تصویریں کھنچوانے کے لیے داڑھیاں رکھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرار کے بعد وہ اپنا چہرہ کسی حد تک تبدیل کر سکیں۔
لباس اس لیے چھپایا کہ ان کو ملنے والے سرکاری کپڑوں پر پی او ڈبلیو (یعنی جنگی قیدی) کی مہریں لگا دی گئی تھیں۔
یہ فرار آسان نہیں تھا اور وہ بھی اس قدر سخت سیکورٹی میں۔ انڈین فوج نے قید خانوں کو فول پروف بنایا تاکہ کوئی بھاگ نہ سکے۔ کیمپ میں خاردار تاروں کی پانچ قطاریں تھیں، پچاس 50 گز کے فاصلے پر واچ ٹاور بنے تھے اور ہر ایک پر سرچ لائٹ تھی ،جبکہ ہر 20 گز پر ایک ٹیوب لائٹ تھی۔
حراست میں رہنے کے چند دن بعد ہی دونوں کزنز میجر طارق پرویز اور میجر نادر پرویز نے کچھ اور افسروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور اب بھاگنے کا باقاعدہ منصوبہ تیار ہوا۔

فیصلہ ہوا کہ اور تو کوئی راستہ نہیں، کیوں نہ ایک سرنگ کھودی جائے۔ سرنگ کھودنے کے لیے غسل خانوں کی قطار میں آخری غسل خانے کا انتخاب ہوا۔ یہ غسل خانہ کیمپ کے باہر کی دیوار کے قریب ترین تھا اور یہاں ایک کونے میں بلب کی روشنی نہیں پہنچتی تھی۔
یہیں سرنگ کھودی جانی تھی۔ سرنگ کھودی کیسے جائے گی، یہ مسئلہ بھی جلد ہی حل ہو گیا۔
لیفٹیننٹ جنرل (ریٹائرڈ) طارق پرویز بتاتے ہیں کہ سرنگ کھودنے کے لیے کمرے میں کپڑے لٹکانے کے لیے لگی سریے کی ایک کنڈی استعمال کرنے کا فیصلہ ہوا۔
مگر غسل خانے کا فرش پکا تھا اور توڑتے تو شور ہوتا۔ انڈین فوجی 24 گھنٹے سر پر کھڑے رہتے تھے، لیکن اس کا حل بھی نکال لیا گیا۔
فتح گڑھ چھاؤنی راجپوت رجمنٹ کا ٹریننگ سینٹر تھا۔ یہاں کیمپ کے ساتھ ہی فائرنگ رینج تھی جہاں انڈین سپاہی رائفل فائرنگ کی مشق کرتے تھے۔ ان کی مشق کے اوقات کار نوٹ کیے گئے۔
طارق پرویز بتاتے ہیں: ’پہلا ہتھیار جو سرنگ کے لیے استعمال ہوا وہ کنڈی تھی۔ وہ فائر کرتے ادھر میں ٹھک سے سریے سے ضرب لگاتا۔ وہاں فائر ہوتا، یہاں ٹھک ٹھک ٹھک۔۔۔ ایسا کرتے کرتے ہم نے فرش توڑ دیا۔‘
ایسا کرتے کرتے سرنگ کا سوراخ تو بن گیا مگر اب مشکل یہ تھی کہ اسے چھپایا کیسے جائے۔ ایک بار پھر قیدی افسروں کی خفیہ ’کانفرنس‘ ہوئی۔
اس تحریر میں ایسا مواد ہے جو Google YouTube کی جانب سے دیا گیا ہے۔ کسی بھی چیز کے لوڈ ہونے سے قبل ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کیونکہ یہ ممکن ہے کہ وہ کوئی مخصوص کوکیز یا ٹیکنالوجیز کا استعمال کر رہے ہوں۔ آپ اسے تسلیم کرنے سے پہلے Google YouTube ککی پالیسی اور پرائیویسی پالیسی پڑھنا چاہیں گے۔ اس مواد کو دیکھنے کے لیے ’تسلیم کریں، جاری رکھیں‘ پر کلک کریں۔
YouTube پوسٹ کا اختتام
خوش قسمتی سے انھی افسران میں ایک پاکستان کی انجینیئرز کور کے افسر میجر رضوان بھی تھے۔ انھیں اس منصوبے میں شامل کیا گیا اور کہا گیا کہ وہ ایک ایسا ڈھکن بنائیں جس سے سوراخ چھپ جائے اور تلاشی کے دوران یہ پتا نہ چلے کہ یہ فرش یہاں سے اکھڑا ہوا ہے۔ میجر رضوان کی مدد سے لوہے کی چارپائیوں میں سے تاریں نکال کر مین ہول کور بن گیا۔
اب وہیں باورچی خانے سے ایک بڑی چھڑی چرائی گئی اور یوں ایک چھری سے سرنگ کھودنے کا کام شروع ہوا۔ چھاؤنی کے ساتھ ہی دریا تھا تو زمین قدرے نرم تھی۔
طارق پرویز بہت فخر سے بتاتے ہیں کہ ’ایک کچن کی چھری تھی اور ہم نے پورا ٹنل بنا دیا۔‘
اگلا مرحلہ تھا کہ کھدائی سے نکلنے والی مٹی کا کیا کرنا ہے۔ اس کے بارے میں طارق پرویز نے بتایا کہ انھوں نے لوٹوں میں مٹی بھرنی شروع کی اور اسے بیت الخلا کے نیچے خندق میں پھینکنا شروع کر دیا۔
وہ بتاتے ہیں کہ سرنگ کی کھدائی میں شامل افسران کو گروپس میں تقسیم کیا گیا۔ کچھ کی ذمہ داری سرنگ کھودنے کی تھی، کچھ کا کام سکیورٹی اور انڈین سنتریوں پر نظر رکھنا تھا اور تیسرا گروپ مٹی کو ٹھکانے لگانے کا ذمہ دار تھا۔
طارق پرویز ہنستے ہوئے کہتے ہیں: ’انڈین فوجیوں نے کسی موقع پر یہ غور نہیں کیا کہ خندق کی گہرائی کم ہو رہی ہے اور آہستہ آہستہ مٹی کا لیول اونچا ہو رہا ہے۔'
جنوری 1972 میں شروع ہونے والا سرنگ کی کھدائی کا کام اگلے سات ماہ تک جاری رہا۔

فتح گڑھ سے فرار
طارق پرویز کے ہمراہ فرار ہونے والے فوجی افسر کیپٹن نور احمد قائم خانی نے حکایت جریدے کے مدیر عنایت اللہ کے ہمراہ اس فرار کی پوری داستان اپنی کتاب ’فتح گڑھ سے فرار تک‘ میں رقم کی ہے۔
وہ لکھتے ہیں کہ انڈین افسران آ کر بڑھکیں مارتے تھے کہ ان کے کیمپ کی سیکورٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہاں سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ ایسے میں ایک جانب چند پاکستانی فوجی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تو دوسری جانب جس وقت یہ مکالمے چل رہے ہوتے، چند قدم کے فاصلے پر کئی فٹ گہری سرنگ کھودنے کا کام جاری ہوتا تھا۔
طارق پرویز بتاتے ہیں جب چیکنگ کے لیے انڈین فوجی آتے تو سب لڑکے بھاگتے اور غسل خانوں میں لباس تبدیل کرتے۔ مگر اُس باتھ روم والا نہیں نکلتا تھا جہاں سرنگ کھودی جا رہی ہوتی تھی اور وہ مسلسل نہاتا ہی رہتا۔
کیپٹن نور قائم خانی لکھتے ہیں کہ 16 ستمبر 1972 تک سرنگ کیمپ کی حدود سے بھی نکل گئی تھی تو اس کے بعد میجر نادر پرویز، طارق پرویز اور کیپٹن نور سمیت پانچ افسران نے منصوبہ بنایا کہ وہ 17 ستمبر کی رات انڈین فوج کی جانب سے قیدیوں کی گنتی کے بعد وہاں سے نکلیں گے۔
سترہ ستمبر کی شب پہلے میجر نادر پرویز، ان کے کزن میجر طارق پرویز اور کیپٹن نور قائم خانی نکلے، جبکہ ان کے چند گھنٹے بعد کیپٹن ظفر حسن گل اور لیفٹیننٹ یاسین کیمپ سے نکلے۔ ان فوجیوں نے پاکستان سے آیا یونیفارم پہنا اور سرنگ سے نکلے۔ اس کی وجہ یہ فیصلہ تھا کہ اگر گولی لگی تو اپنی فوج کے یونیفارم میں مریں گے۔
طارق پرویز بتاتے ہیں کہ ہم سب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو افسران بھی ٹولیوں کی صورت میں نکلنا چاہتے ہیں وہ اپنا منصوبہ تیار کریں اور کسی دوسرے گروپ کو اس کے بارے میں نہ بتائیں، تاکہ پکڑے جانے کی صورت میں تشدد کے باوجود ہم ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہ بتا سکیں۔
وہ بتاتے ہیں کہ پانچ افسران کے علاوہ اور کوئی باہر اس لیے نہیں نکلا کہ ان کے پاس نہ تو انڈین کرنسی تھی اور نہ ہی ایسا لباس جس پر پی او ڈبلیو کی مہر ثبت نہ ہو۔
’اس کے علاوہ فرار کا فیصلہ ایک مشکل قدم ہے۔ سب جانتے تھے کہ ایک دن پاکستانی فوجی قیدی وطن واپس پہنچ جائیں گے، مگر فرار کے دوران پکڑے جانے کی صورت میں وہ گولی کا نشانہ بن سکتے تھے۔ اس لیے پانچ افسران کے علاوہ کسی نے خطرہ نہ لیا۔‘
فرار ہونے والے فوجیوں میں سے پہلے تین (میجر طارق، میجر نادر اور کیپٹن نور احمد قائم خانی) نے باہر نکل کر لباس تبدیل کیا اور اپنی داڑھی شیو کی۔ اس طرح ان کا حلیہ ان تصویروں سے کچھ مختلف ہو گیا جو آئندہ چند روز میں انڈین اخباروں میں چھپنی تھیں۔
ان فوجیوں کے فرار کی خبر جب انڈیا کے اخباروں میں چھپی تو پاکستان میں موجود فوجی قیادت نے انڈیا سے منسلک سرحد پر یہ حکم پہنچایا کہ سرحد یا لائن آف کنٹرول پار کرنے کی کوشش کرنے والوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔

تاہم فرار ہونے والے افسران پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ بارودی سرنگوں کی وجہ سے سرحدی علاقوں کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ وہ سمندری راستے یا نیپال میں پاکستان کے سفارتخانے پہنچ کر وطن واپسی کا انتظام کریں گے۔
لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق پرویز کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس صرف 10 روپے رہ گئے تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب اور تو کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے سنیما میں پاکیزہ فلم دیکھی جائی۔
’فلم دیکھی اور باہر آ کر تازہ جوس پیا۔ اور پھر ہم بیٹھ گئے کہ اب تو پیسے ختم ہو گئے۔ ہم نے یہاں کچھ مسلمان خاندانوں سے رابطے کا فیصلہ کیا۔ اور بھی کچھ لوگوں سے ملاقات کی لیکن کوئی بھی مدد کے لیے تیار نہ ہوا۔‘
آخر کار ان تینوں نے جماعت اسلامی ہند کے ایک رکن سے رابطہ کیا جنھوں نے ان تینوں کو لکھنؤ کے ٹکٹ لے دیے اور لکھنؤ میں کچھ لوگوں کے نام خط لکھ دیے تاکہ ان کی مدد کی جا سکے۔
’تم تینوں وہی ہو جو فتح گڑھ سے بھاگے ہو‘
لکھنؤ پہنچ کر ان کی جس خاندان ملاقات ہوئی، اُنھوں نے ان کا قصہ سننے کے بعد کہا کہ ’تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو۔ تم تینوں وہی ہو جو کچھ دن پہلے فتح گڑھ کی جیل سے بھاگے ہو۔‘
طارق پرویز کے مطابق اس خاندان کے ایک بزرگ نے ان کی مدد کی اور انھیں 30 ستمبر کو نیپال کی سرحد پار کروا دی۔
یہاں سے وہ 70 میل پیدل سفر کر کے نیپال کے سرحدی علاقے بھیروا پہنچے اور یہاں مسلمانوں کے ایک دیہات کی مسجد میں قیام کیا۔ ادھر سے جہاز کا ٹکٹ خریدا گیا اور نادر پرویز کھٹمنڈو روانہ ہوئے جہاں انھوں نے پاکستان کے سفارتخانے پہنچ کر باقی دونوں افسران کے لیے بھی ٹکٹ بھجوائے۔
طارق پرویز نے بی بی سی کو بتایا: 'وہ لمحہ مجھے کبھی نہیں بھولتا جب میں کھٹمنڈو ایئرپورٹ سے نکل کر پاکستان سفارتخانے کی جانب جا رہا تھا۔ مجھے دور سے سفارت خانے کی عمارت پر اپنے ملک کا جھنڈا لہراتا ہوا نظر آیا اور فرط جذبات سے میری آنکھوں میں آنسو آگئے۔'
یہ تینوں پی آئی اے کی پرواز سے گیارہ اکتوبر کو کراچی پہنچے جہاں ان کی سکیورٹی کلیئرنس ہوئی اور اس کے بعد اپنے اہلخانہ سے ملنے کی اجازت ملی۔
طارق پرویز بتاتے ہیں: ’جہاز سے اترا تو سب سے پہلے میں نے سجدہ کیا کہ اپنی مٹی پر واپس آ گیا ہوں۔ ہماری حالت ایسی تھی کہ گھر والے پہچان نہیں پائے۔ لیکن وہ وقت بہت جذباتی تھا۔ میری ماں بار بار مجھے گلے لگاتی تھیں۔‘
وہ قیدی جو خوش قسمت ثابت نہ ہوئے
یہ پانچ افسران تو قید سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے مگر ہزاروں پاکستانی فوجیوں اور سول آرمڈ فورسز کے اہلکاروں میں دوسرا کوئی اس قدر خوش قسمت ثابت نہ ہو سکا۔ کئی جنگی قیدیوں نے فرار کی کوششیں بھی کیں مگر وہ ناکام ثابت ہوئیں۔
انڈین جنگی قیدیوں کے لیے بنے کیمپوں میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے والے ان جوانوں اور افسران میں سے دو میجر ریٹائرڈ صابر حسین اور میجر ریٹائرڈ نعیم احمد بھی شامل تھے۔
میجر صابر حسین کا تعلق آزاد کشمیر رجمنٹ سے تھا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو وہ شنکیاری میں اپنی یونٹ کے ساتھ تھے اور انھیں وہاں حکم ملا کہ فوراً کراچی پہنچو اور وہاں سے ڈھاکہ روانہ ہو۔
'میں نے 65’ کی جنگ بھی لڑی مگر وہ ایک منظم جنگ تھی، منصوبہ بندی کی گئی تھی، اور اسی کے مطابق تعیناتیاں ہوتی تھیں۔ لیکن 1971 کی جنگ میں ایسا کچھ نہیں تھا۔'
میجر صابر بتاتے ہیں کہ مشرقی پاکستان پہنچ کر نہ انھیں راستوں کا علم نہیں تھا نہ ہی ساتھیوں پر اعتبار باقی رہا۔
’ہمارے اپنے بنگالی فوجی باغی ہو گئے تھے۔ جس کو جہاں موقع ملتا نقصان پہنچا دیتا۔ کوئی قتل و غارت کر رہا تھا، کوئی راستہ غلط دکھاتا۔ ہم تو ہر طرف سے دشمن میں گھرے ہوئے تھے۔ مشرقی پاکستان کے لوگ ہمارے دشمن، وہاں کے افسر ہمارے دشمن، وہاں کے سپاہی ہمارے دشمن، ہمیں جو گائیڈ ملتے کہ راستے کی رہنمائی کریں گے، ان کا بھی اعتبار نہیں تھا۔ وہ بھی بنگالی تھے۔ ہاں بہار کے لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا اور خلوصِ نیت سے ساتھ دیا۔‘

’انڈین افسر کی ڈانٹ ہتک آمیز لگتی‘
جب مشرقی پاکستان میں جنرل امیر عبداللہ خان نیازی نے انڈین فوج کے جنرل جگجیت سنگھ اروڑا کے سامنے ہتھیار ڈالے تو اس بارے میں اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے میجر صابر نے بتایا کہ پہلے تو انھیں یقین نہیں آیا کہ شکست ہو گئی ہے اور اب جنگی قیدی بننا ہے۔
’ہم نے کلکتہ سے بہار کا سفر بحری جہاز میں کیا۔ کسی کو کچھ علم نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے اور ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ وہاں ہمیں چار، پانچ دن پرانا پکا ہوا کھانا ملتا، نجانے کہاں پکتا تھا۔ ہم سمندر کے پانی سے روٹی کو دھوتے، پھر اسے خشک کرتے تھے۔ یہ ہمارا کھانا تھا۔‘
میجر صابر بتاتے ہیں کہ انڈین فوجی تو قدرے بہتر تھے، مگر بنگالی فوجیوں کا رویہ خاص طور پر بُرا تھا اور اس عرصے میں اتنا پروپیگنڈا ہو چکا تھا کہ وہ پاکستانی فوجیوں کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔
’دکھ ہوتا تھا کہ جن سے ہم کل تک روبرو بات کرتے، آج ان کے سامنے سر جھکا کر بات کر رہے ہیں۔ ہمیں گھنٹوں کھڑا رکھا جاتا، سخت سردی میں گھنٹہ، دو گھنٹہ ہم کھڑے رہتے۔ فزیکل سزا تو نہیں دی جاتی کہ تھپڑ مار دیا۔ فوجی سزائیں عام تھیں۔ اور پھر یہ اپنے اندر کی جنگ تو بہت بڑی تھی۔ ایک عام حالت میں اپنا افسر بھی ڈانٹے تو بڑا دکھ ہوتا ہے، مگر ایک انڈین ڈانٹ رہا ہوتا تو وہ ہتک آمیز لگتا۔‘
وہ بتاتے ہیں کہ قید میں چھ ماہ تک وہ اپنے اہلخانہ سے رابطہ نہ کر سکے۔ مشرقی پاکستان جاتے وقت میجر صابر حسین کی بیٹی اس وقت نو ماہ کی تھی۔
انھیں چھوڑ کر جانے کا وہ وقت کس قدر کربناک ہوگا اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ 50 سال گزرنے کے بعد بھی وہ اپنی بیٹی سے الوادعی ملاقات کا ذکر کرتے میجر صابر حسین آبدیدہ ہو گئے۔
یہ بھی پڑھیے
’وہ لمحہ مجھے ساری زندگی نہیں بھولا۔ جب میں جا رہا تھا تو آخری بار میں نے اسے گلے لگایا۔ قید کے دوران وہی لمحہ میرے ذہن میں گھومتا رہا۔‘
قید کے دنوں کا ذکر کرتے ہوئے میجر صابر حسین نے اپنے سگریٹ چھوڑنے کا دلچسپ قصہ بھی سنایا۔
’سگریٹ ایک عجیب لعنت تھی کہ اس پر خوب لڑائیاں ہوتیں۔ تمام ہی فوجی افسران سگریٹ کے شوقین تھے۔ روٹی کے بغیر رہ لیتے مگر سگریٹ کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ اور سگریٹ پر ہی لڑائی بھی ہوتی۔ میرے اردلی نے میرے لیے خاصے سگریٹ جمع کر رکھے تھے۔ میں نے جب دیکھا کہ سگریٹ پر اس قدر جھگڑے ہو رہے ہیں تو بس میرا دل اٹھ گیا۔ میں نے اپنے سگریٹ کا سارا سٹاک فوجیوں میں تقسیم کر دیا اور کہا کہ لڑو مت اور یہ پیو۔ لیکن اس دن کے بعد خود میں نے سگریٹ پینی چھوڑ دی تھی۔‘
میجر صابر حسین کے مطابق انھیں واپسی کا اندازہ اس وقت ہوا جب بیمار قیدیوں کو کیمپ سے لے جانا شروع کیا گیا۔
’اپریل 1974 میں بہار سے ہمیں ٹرکوں پر رانچی لے گئے۔ وہاں سے ایئر پورٹ اور پھر جہاز کے ذریعے واپس پاکستان لایا گیا۔‘
وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان پہنچ کر مناظر بہت جذباتی تھے۔ مگر اس سب کے دوران ان کی توجہ کا مرکز ان کی بیٹی تھی۔

’جب میری قید ختم ہوئی تو میری بیٹی تقریباً تین سال کی ہو گئی تھی۔ میں واپس آیا تو وہ ایک دم میری گود میں آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے واپس آنے پر اگر سب سے زیادہ خوشی تھی تو وہ اپنی بیٹی سے ملنے کی تھی۔‘
مگر اس قید کا ان کی شخصیت اور کریئر دونوں پر ہی اثر پڑا۔ جو قیدی واپس آئے انھیں یونٹوں میں دوبارہ گھلنے ملنے میں وقت لگا۔
میجر صابر حسین بتاتے ہیں کہ واپسی کے بعد جب وہ یونٹ پہنچے تو وہاں افسران اور خود میں فرق محسوس ہوتا تھا۔
’ہمیں نارمل ہونے میں بہت وقت لگا۔ ہم خود کو کمتر سمجھتے تھے کہ ہم دشمن کی قید کاٹ کر آئے ہیں۔ یہاں بھی کوئی نہ کوئی طعنہ مارتا۔ مگر بتدریج بہت سی چیزوں کے عادی ہو گئے۔‘
’سنہ 1971 کی جنگ ہمارے لیے کبھی ختم نہیں ہوئی‘
خوش قسمتی یہ تھی کہ میجر صابر حسین جیسے ہزاروں فوجی وقت کے ساتھ کسی حد تک نارمل زندگی میں لوٹ آئے، مگر کئی ایسے تھے جن کا امتحان ابھی باقی تھا اور کئی فوجیوں اور ان سے جڑے خاندانوں کے لیے یہ جنگ کئی دہائیوں تک جاری رہی جن میں سے ایک میجر نعیم احمد تھے۔
میجر نعیم احمد کی بیٹی سنعیہ احمد نے بی بی سی سے بات کی اور اپنے والد کے بارے میں بتایا۔ وہ کہتی ہیں کہ 1971 کی یہ جنگ ان کے لیے اور ان کے بھائیوں کے لیے کبھی ختم نہیں ہوئی تھی۔
وہ بتاتی ہیں کہ ان کے والد اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے اور انھیں فوج میں شمولیت کی اجازت ہی اس شرط پر ملی کہ وہ جنگ کرنے والی ڈویژن میں نہیں ہوں گے۔
وہ بتاتی ہیں کہ مشرقی پاکستان پہنچنے کے بعد ان کے والد میجر نعیم احمد کا کام فوجی دستوں تک اسلحہ و بارود وغیرہ پہنچانا تھا۔
اپنے والد کے پکڑے جانے کا واقعہ سناتے ہوئے سنیہ نے بتایا کہ جب ان کو ہتھیار ڈالنے کی خبر ملی تو انھیں حکم دیا گیا کہ تمام بارود تباہ کر دیا جائے تاکہ وہ دشمن کے ہاتھ نہ لگ سکے۔

سنعیہ احمد نے بتایا کہ ان کے والد اور ان کے ساتھیوں کو امیونیشن تباہ کرنے کا مقام پر جانا تھا جو ان کے مورچوں سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا لیکن غلطی سے وہ غلط مقام پر چلے گئے اور ایک گھنے جنگل پہنچے۔
’وہاں پہنچ کر احساس تو ہوا کہ یہ درست مقام نہیں ہے مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی اور انڈین فوجیوں نے حملہ کر دیا۔‘
سنعیہ احمد بتاتی ہیں کہ حملہ آور انڈین فوجیوں کا تعلق ایلیٹ گروپ سے تھا جو جنگ میں ماہر تھے اور پاکستانی فوج کے 150 اہلکار وہ تھے جو جنگجو دستوں سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔
’پاکستانی فوجی تین گھنٹے تک لڑتے رہے۔ اتنی بہادری سے لڑے کہ انڈین فوجی دستے کی کمان کرنے والے میجر جسوال نے بعد میں کہا کہ یہ افسر انفنٹری دستوں کی طرح لڑتے رہے ہیں۔‘
اس لڑائی کے دوران سنعیہ احمد کے والد میجر نعیم ایک مارٹر شیل لگنے سے زخمی ہو گئے اور ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔
سنعیہ احمد بتاتی ہیں کہ چہرے پر شیل سے لگنے والے زخموں کے باعث انھیں پہچاننا مشکل ہو گیا تھا اور وہ کئی ماہ تک مسنگ پرسنز کی فہرست میں رہے اور پاکستان میں لوگ تعزیت کے لیے ان کے والدین سے ملنے آتے رہے۔
لیکن بالآخر جہاں ان کا علاج ہو رہا تھا اس ہسپتال میں ان کے دوست نے انھیں پہچان لیا۔ سنیہ بتاتی ہیں کہ طبیعت سنبھلنے کے بعد انھیں جنگی قیدی کے طور پر رانچی میں قائم قید خانے میں بھیج دیا گیا۔

’میرے والد جب اس قید خانے پہنچے تو ان کے پاس کپڑے نہیں تھے۔ پھر انھوں نے سوئی دھاگہ لیا اور خود ہی اپنا لباس تیار کیا جس کے بارے میں وہ بہت فخر سے بتاتے تھے۔ انھیں بہت فخر تھا کہ قید میں انھوں نے درجنوں افسروں اور جوانوں کو قران مجید پڑھنا سکھایا۔‘
’والد کو دورے پڑنے لگے‘
سنعیہ احمد بتاتی ہیں کہ 1974 میں ان کے والد میجر نعیم احمد انڈیا سے واپس آ گئے اور وہ بظاہر ایک نارمل، صحت مند انسان تھے۔
’انھوں نے شادی کی اور پھر بچوں کی پیدائش ہوئی۔ ابو اتنا پیار کرتے تھے کہ ہم سے لاڈ کرنے کے لیے وہ ہمیں پیسے تک آفر کرتے۔ وہ بہت اچھے گلوکار تھے اور انھوں نے مجھے نعت پڑھنی سکھائی۔ میں میوزک کے مقابلوں میں حصہ لیتی اور وہ گھنٹوں پریکٹس کرواتے۔ مگر 1984 میں ان کے ذہن پر اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔‘
سنعیہ احمد بتاتی ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے والد کی نہ صرف یادداشت کمزور ہوتی گئی بلکہ ان پر ہذیانی کیفیت بھی طاری ہونے لگی۔
وہ ایسی باتیں کرتے جو حقیقت نہ ہوتیں مگر انھیں وہی سچ لگتا۔ یہ صورتحال ان کے دفتر اور قریبی ساتھیوں نے بھی نوٹ کرنی شروع کر دی اور پھر چھ ماہ کے لیے انھیں نفسیاتی علاج کے ہسپتال میں داخل کرنا پڑا۔
اس دوران ان میں ڈیمینشیا، ڈپریشن اور ہیلوسینیشن جیسی بیماریوں کی تشخیص ہوئی۔
سنعیہ کے ذہن پر اپنے والد کی یادداشت کا ایک مخصوص واقعہ آج بھی نقش ہے۔
’ابو ہمیشہ ہمارے ساتھ بہت خوش رہتے۔ ڈرائیونگ ان کا مشغلہ تھا مگر ان کے اعصاب کام کرنا چھوڑ رہے تھے تو وہ ڈرائیو بھی نہیں کر پاتے۔ یہ بات ان کے لیے تکلیف دہ تھی۔ ایک بار سات ستمبر کو وہ ہمیں ایئر شو دکھانے لے گئے۔ وہ گاڑی چلا رہے تھے اور ایک موقع پر وہ پیچھے مڑے۔ وہ ہمیں کچھ کہنا چاہ رہے تھے مگر ان کے منہ سے الفاظ نہیں نکل پائے۔ ہم بہن بھائی بہت کم عمر تھے مگر انھیں حوصلہ دیا کہ کوئی بات نہیں۔ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ ابو اب شاید بول بھی نہ سکیں۔‘

’دو دہائی بعد دماغ میں مارٹر شیل کے ذرات پائے گئے‘
بتدریج میجر نعیم کے بولنے اور چلنے پھرنے کی صلاحیت کم ہونے لگی۔ سنہ 1989 میں فوج نے انھیں ایک سال کے لیے یونیفارم پہننے سے روک دیا اور یہ یہ میجر نعیم کے لیے بہت سخت مرحلہ تھا۔
سنعیہ احمد بتاتی ہیں کہ ان کے والد پہلے ہی شدید ذہنی دباؤ کے شکار تھے، مگر یونیفارم نہ پہننے کا دکھ ہر چیز پر حاوی ہو گیا اور اس موقع پر انھوں نے فیصلہ کیا کہ وہ فوج سے ریٹائرمنٹ لیں گے۔
’جس دن انھوں نے آخری بار یونیفارم پہنا، اس دن وہ خاص طور پر تیار ہوئے اور یہ لمحے یادگار بنانے کے لیے بچوں کے ساتھ تصویریں بھی کھنچوائیں۔‘
ریٹائرمنٹ کے بعد میجر نعیم نے فوج کے فلاحی ادارے میں ملازمت شروع کی مگر کچھ عرصے بعد ان پر مرگی کا دورہ پڑا۔ اس کے بعد انھیں سی ایم ایچ پہنچایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے سی ٹی سکین کا مشورہ دیا۔
یہ بھی پڑھیے
’جب ابو کا سی ٹی سکین ہوا تو ڈاکٹر حیران رہ گئے۔ انھیں جو مارٹر شیل 1971 میں لگا تھا اس کے سینکڑوں ٹکڑے وہیں موجود تھے اور وہ 22، 23 سال بعد پہلی بار دیکھے گئے۔ تب جا کر سمجھ آیا کہ ان کی تمام بیماریاں کس کس وجہ سے تھیں۔‘
سنعیہ احمد نے بتایا کہ اس تشخیص کے بعد ہسپتال آنا جانا معمول بن گیا تھا اور وہ ہفتوں کوما میں رہتے اور ڈاکٹر کہتے کہ اب بس ان کے لیے دعا کریں۔
’مگر وہ ہمیشہ بیماری سے لڑتے اور گھر آ جاتے۔ پھر سنہ 2000 میں انھیں ایک اور دورہ پڑا تو وہ 10 ہفتے سی ایم ایچ میں داخل رہے۔ اس دوران وہ کوما میں تھے۔ وہاں ایک نیوروسرجن نے جب ان کی میڈیکل ہسٹری پڑھی تو پہلی بار کسی ڈاکٹر نے بتایا کہ انھیں سیریبرل ایٹروفی ہے یعنی ان کا دماغ سر میں موجود شیل کے ذرات کی وجہ سے کئی سالوں سے سکڑ رہا تھا۔‘

اپنے والد کی زندگی کے آخری دن کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے سنعیہ آبدیدہ ہو گئیں۔
وہ بتاتی ہیں کہ مغرب کا وقت تھا اور جب وہ اپنے والد کے کمرے سے باہر نکلیں تو انھوں نے نم آنکھوں سے دعا مانگی کہ ان کے لیے وہی ہو جو بہتر ہے۔
’میں نے ہمیشہ ان کی واپسی (یعنی صحتیابی) کی دعا مانگی تھی کیونکہ وہ ایک فائٹر تھے۔ اس سے پہلے میں نے کبھی یہ دعا ہی نہیں کی تھی۔ مجھے آج بھی نہیں پتا کہ میں نے یہ کیوں کہا۔‘
کچھ لمحوں بعد سنعیہ جب دوبارہ اپنے والد کے کمرے میں گئیں تو انھوں نے اپنے والد سے باتیں شروع کر دیں جو کومے کے سبب بے خبر سو رہے تھے۔
’میں نے ان کا ہاتھ سہلایا تو انھوں نے اپنے ہاتھ کو حرکت دی اور میرا ہاتھ تھام لیا۔ ابو اتنے عرصے سے کوما میں تھے مگر وہ تھوڑا سے اٹھے، اپنا سر اٹھایا، کندھے اٹھائے، اور تھوڑا سا کھانسے۔ پھر انھوں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور پھر ان کی سانس کی ڈوری ٹوٹ گئی۔‘